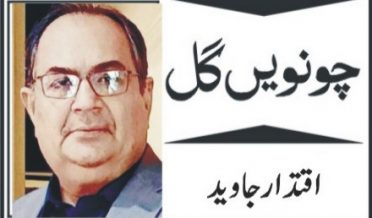سعادت حسن منٹو کی سب سے بڑی خوبی وہ کردار ہیں جو کبھی مرتے نہیں۔کہانی میں مر کر بھی نہیں۔منٹو کے یہ زندہ کردار کہانی کے ایک خاص پلاٹ کے طے شدہ رستے پر چلنے کے بجائے اپنی راہیں خود بناتے ہیں جن کے ساتھ ساتھ کہانی ایک موہوم سائے کی طرح چلتی ہے۔ان کرداروں کا پس منظر اور پیش منظر بہت واضح ہے۔یہ حالات کے بطن سے جنم لے کر سماج کی تاریکی میں سانس لیتے کبھی سرگوشی کرنے سے بھی ڈرتے ہیں اور کبھی گلا پھاڑ کر یوں چیختے ہیں کہ جیسے کائنات کی سماعتوں ہی کوچھید ڈالیں گے۔کبھی اتنی تیز بھاگتے ہیں کہ کہانی کا سانس پھول جاتا ہے اور کبھی اتنی آہستہ کہ پاوں کی آہٹ ساری تھکن کی اذیت ٹھہر ٹھہر کے سناتی ہے۔منٹو کے سبھی کردار بہت شفاف ہیں،بھلے ان کا پورا وجود گندگی ہی میں کیوں نہ لتھڑا ہو۔ان کا اندر اور باہر ،سب صاف دکھائی دیتا ہے۔یہ کبھی بازارِ حسن کی پر پیچ تاریک گلیوں میں بات کرتے ہیں اور کبھی سرکنڈوں کے پیچھے اپنی پہچان چھپانے کی کوشش کرتے ہیںلیکن چھپ نہیں پاتے ،ہم انہیں اندر تک دیکھ لیتے ہیں۔بہت غور کریں تو شاید ان کی دھڑکنیں سنائی دیں اور سوچوں میں چھپے راز بھی۔میں جب بھی منٹو کے افسانے لیے بیٹھتی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر کردار میں منٹو خود موجود ہے۔وہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔سیاہ اور سفید،دونوںرنگوں میں منٹو خود ہی ہے۔اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ منٹو خود نہیں،ان کرداروں میں مجھ سمیت پورا معاشرہ ہے۔اس معاشرے کی ساری گندگی،بدبو ،مکاری اور استحصال سمیت سب کا سب موجود ہے۔جیسے یہ کردار ایسا آئینہ ہیں جن میں، میں آپ سب اپنی اپنی شکلیں دیکھ سکتے ہیں۔ہاں،یہ الگ بات ہے ہم پہچان نہ پائیں اور خود کو کسی اور کا نام دے کر اپنے گناہ کی سیاہی سے صرفِ نظر کرلیں۔میں ہر روز منٹو کے کرداروں سے ملتی ہوں۔ ہر گلی اور محلے کی نکڑ سے لے کر بڑی اور مصروف سڑکوں پہ پھیلے ہجوم تک میں وہ سب لوگ زندہ دکھائی دیتا ہے جو میز پر اکڑوں بیٹھے منٹو کے قلم سے تخلیق پارہاتھا۔جیسے منظر نامہ بدل گیا ہے ،لیکن کہانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔وہ پھر سے دہرائی جارہی ہے،جس طرح ہمارے ہاں پرانے گانوں کا ری میک ہوتا ہے۔آواز اور ساز بدل جاتے ہیں لیکن الفاظ وہی رہتے ہیں۔کبھی دھن میںبھی معمولی تبدیلی آجاتی ہے لیکن گیت وہی رہتا ہے،گیت کے بول ویسے ہی رہتے ہیں۔ منٹو بہت چالاک آدمی تھا،شایداس نے وہ پلاٹ سمجھ لیا تھا جس پر قدرت نے ہمارے معاشرے کو ترتیب دیا ۔اس نے اسی ترتیب یعنی
معاشرے کے مستقل پلاٹ پر اپنی کہانیان لکھیں اور کردار بھی اسی طرح سے تخلیق کردیے جیسے ان کا ڈی این اے بہت پہلے کہیں ازل میں تخلیق ہوا تھا۔اس ڈی این ایکو جیسے منٹو نے ڈی کوڈ کرلیا تھا۔منٹو کی یہی مہارت ان کرداروں کو مرنے نہیں دیتی اور یہ اپنا نام پتا تبدیل کرکے بار بار ہمارے سامنے آجاتے ہیں۔سب کا سب وہی ہے ،دہائیوں پہلے جیسا۔ہر بار بس بوتل تبدیل ہوتی ہے،شراب وہی رہتی ہے۔پرانی ہونے کے ناتے اب اس کا نشہ بھی بڑھا ہے اور قیمت بھی۔مجھیاپنے معاشرے میں بشن سنگھ اکثر دکھائی دیتا ہے جو تقسیم کادرد لئے اس الجھن میں ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں
ہے۔75سال میں اس کے پاوں پہلے سے کہیں زیادہ سوجھ گئے ہیں۔اسے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا پتا ملا نہ اپنی بیٹی روپ کور کا ۔وہ اب بھی دہرا رہا ہے اوپڑدی گڑگڑدی انیکس دی بے دھیانادی منگ دی دال اف دی لالٹین۔یہ بے ترتیب اور بے معنی سے الفاظ کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔لوگ پہلے اسے دیکھتے تھے،اب گزرتے ہوئے دیکھتے بھی نہیں۔لیکن اسے کوئی دلچسپی کہ کوئی اس کا دکھ سمجھتا ہے یا نہیں۔وہ اپنی کھوئی ہوئی دنیا تلاش کررہا ہے جو اسے 75سال سے نہیں ملی۔اسے تب بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ ہندوستان چلا جائے یا پھرپاکستان میں رہے۔وہ ادھر رہتا یا پھرواہگے کے اس پار چلا جاتا،اسے اپنا ٹوبہ ٹیک سنگھ ملنا تھا اور نہ ہی روپ کور۔ملیں گے بھی تو کیسے،دونوں کو لوگوں نے مالِ غنیمت کی طرح لوٹ لیا۔اب نہ اس کا اپنا شہر ہے اور نہ ہی بیٹی کے سر پہ دوپٹا۔میں سوگندھی سے بھی ملتی ہوں ،وہ ایک عورت ہے لیکن حالات نے اسے طوائف بنا دیاہے۔وہ طوائف ہے لیکن مکارنہیں۔اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ گھر آباد کرے،اس کے بچے ہوں ۔اس کی مامتا بھرپور زندگی سے سرشار ہوکر ایک ایک لمحے کو خوب جئے۔لیکن ایسا نہیں ہوا ،سب اس کے جسم کے گاہک ہیں،کوئی بھی اس کی روح سے ہم کلام نہیں ہونا چاہتا جو کسی بھی دوسری ماں کی طرح پاک ہے۔سوگندھی بری نہیں ،اس کے اندر کی سچائی کبھی نہیں مرتی ۔سیاست کے بازارِ حسن میں روز پامال ہوتی جمہوریت کی یہ سوگندھی شاید اب بھی یہی چاہتی ہوکہ وہ اپنی روح کی پاکیزگی کے ساتھ زندہ رہے لیکن نسل در نسل اسے پامال کرنے والوںکو اس
سے کوئی غرض نہیں۔کھول دو کا سراج دین بھی اپنی کہانی کو مسلسل دہرائے جارہا ہے۔بہت سال پہلے اسے اپنی بیٹی سکینہ کی تلاش تھی جو تقسیم کے بعد ہجرت کے دوران کھو گئی تھی۔اس نے بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔اس نے ان رضا کاروں کی منت سماجت بھی کی جو بچھڑنے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنوں سے ملا رہے تھے۔جب بوڑھے سراج دین کوکہانی کے آخر پر سکینہ ملی بھی تو ہسپتال کیایک سٹریچر پر جہاں وہ بے حس و بے جان پڑی تھی۔ڈاکٹر نے سٹریچر پر پڑی لاش کی نبض ٹٹولی اور پاس کھڑے سراج دین سے کہاکہ کھڑکی کھول دو۔سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوتی ہے اور انسانی تاریخ خود اپنے آپ سے شرمندہ دکھائی دیتی ہے ۔بوڑھا سراج دین خوشی سے چلاتا ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے ،ہاں زندہ ہے۔ڈاکٹر سر سے پاوں تک پسینے میں غرق ہوگیا۔گھڑی کی سوئیاں گھومتی ہیں اور وقت کا بہتا دریا بڑی تیزی کے ساتھ ماہ و سال کے پلوں کے نیچے سے گزرتاہوا حال تک پہنچتا ہے۔نیوز چینلز پر کسی گمشدہ دعا زہراکی خبر چل رہی ہے۔بریکنگ نیوز کے ساتھ ہی اس کے باپ کا ایک کلپ چلتا ہے، جس میں سراج دین صرف اس لیے خوش ہے کہ اس کی بیٹی زندہ ہے۔یہیں گجرات کا چک کمالہ بھی ہے جہاں 18سال کی معذور لڑکی کا انتقال 4مئی کو ہوا۔اسی روزمرحومہ کی تدفین بھی کردی گئی۔اگلی صبح جب اہلِ خانہ فاتحہ کے لیے قبرستان گئے تو قبر کھلی ہوئی اور لاش غائب تھی۔تلاش کی گئی توکوئی 25میٹر دور ،دو پکی قبروں کے درمیان بے کفن پامال وجود پڑا تھا۔منٹو کا ایشر سنگھ وقت کے ساتھ ساتھ انسان سے جانور بنا اور اب شاید اس درجے سے بھی کہیں پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں کسی اور ہی مخلوق کی جون اختیار کرگیا ہے۔کھلی ہوئی قبر اور میلا کفن ہمارے سماج کی وہ کہانی ہے جسے منٹو نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔اس کے کردار بار بار اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ہم ہر بار ایساہوتے ہوئے دیکھتے ہیں،خوفزدہ بھی ہوجاتے اوروقتی طور پر سہم بھی جاتے ہیں لیکن ٹھنڈے گوشت کو بھنبھوڑنے والے کتوں کاکچھ نہیں کرتے۔بات ایک لاش کی نہیں،اس ایک قبر کی بھی نہیں جسے کھودا گیا یا پھر اس میلے کفن کی بھی نہیں،بات اس معذور میت کی بھی ہے جسے ہم اپنے نظام کا نام دیتے ہیں۔جس پرکبھی ایشر سنگھ ہاتھ ڈالتا ہے اور کبھی وہ رضا کار جنہیں سکینہ کو ڈھونڈنا تھا۔ میں نے کہانامنٹو کے کردار مرے نہیں،زندہ ہیں۔یہ ہمیں روز ملتے ہیں،ہم سے بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔فرق صرف اتنا ہے کہ منٹو نے اپنے بیشتر کردار بازارِ حسن سے چنے تھے جبکہ آج پورے کا پورا سماج ہی بازارِ حسن بنا ہوا ہے۔
 107
107